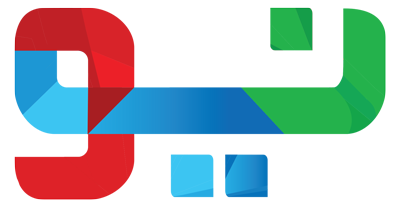معروف ادیب اور انسان دوست خواجہ مظہر صدیقی نے سٹڈی گروپ کے نام سے ایک حلقہِ دوستان قائم کر رکھا ہے۔ حلقہ کیا ہے، شعراء ادباء اور اہلِ دانش پر مشتمل ایک خوبصورت ذہنوں کا جھرمٹ ہے۔ پچھلے دنوں برادرم طاہر بلوچ نے ایک خیالِ مستعار پر دعوتِ فکر دی۔ لکھتے ہیں:
’’فرانسیسی سوشیالوجسٹ بورڈو کے مطابق کلچر اور مذہب دونوں سماج کے طاقتور حلقوں کے مفادات کو سرو serve کرتے ہیں۔ انکا بنیادی کام سماجی ناہمواری کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ناانصافیوں پر ممکنہ ردعمل کو پیدا ہونے سے پہلے لیول کرنا ہے۔ جس طرح مذہب بے شمار ناپسندیدہ حقیقتوں کو غیر منطقی تصورات کے ذریعے بغاوت بننے سے روکتا ہے، اسی طرح کلچر بھی لاتعداد ناپسندیدہ اطوار کو عوامی غیظ و غضب سے محفوظ رکھتا ہے اور صدیوں سے جاری صنفی امتیاز یا نسلی اور لسانی اونچ نیچ کو تبدیلی سے بچا کر اگلی نسل تک منتقل کر دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ منتقل کرتا ہے بلکہ اسے ایسی قدر بنا کر بھی پیش کرتا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے بعض علاقوں میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا، گھریلو تشدد، عزت کے نام پر قتل وغیرہ۔ مذہب ہو یا کلچر دونوں کا یہ فنکشن بڑا دلچسپ ہے کہ اسکے ذریعے ناانصافی اور ناہمواری ایک منطقی طرز زندگی کے طور پر قبول کر لی جاتی ہے اور یہ اگلی نسل تک منتقل بھی کر دی جاتی ہے۔‘‘
یہ پیراگراف ملاحظہ کرنے کے بعد بے اختیار اس پر تبصرہ کرنے کو جی چاہا، لکھنے بیٹھا تو تبصرہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ خیال وارد ہوا کہ اپنے قارئین کو بھی شاملِ خیال کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ اس فقیر کے تبصرے کو معاشرے میں رائج جہالت اور ظلم کی وکالت پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ایک فلسفی کے طور پر حقیقت کی کھوج لگانے کا ایک زاویہ تصور کیا جائے۔ جہالت، جہالت ہے جہاں بھی پائی جائے اور ظلم، ظلم ہے جہاں بھی برپا ہو۔ جہالت اور ظلم کا جواز کسی مذہب یا کلچر میں ڈھونڈنا بجائے خود ایک ظلم ہے۔
فرانسیسی سوشیالوجسٹ کا مطالعہ غالباً اُس کے اپنے مذہب اور معاشرے کا عکاس ہے، وہ معاشرہ جسے وہ خود تاریک دور dark age سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اُس دَور کو دیکھ کر اخذ کیا جانے والا نتیجہ ہے جب پاپائیت اور شہنشاہیت کے صدیوں پرانے گٹھ جوڑ نے یورپی معاشرے میں شدید معاشرتی گھٹن پیدا کر دی تھی۔ وہاں سوچوں پر پہرے تھے، منصبِ انصاف پر جاہل اور متعصب پادریوں کا قبضہ تھا، وہ لوگ جسے چاہتے جادوگر اور باغی قرار دے کر گلوٹین پر مامور جلادوں کو سونپ دیتے۔ اس ظلم اور جبر پر مشتمل فرانسیسی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں کی صورتِ حال منطقی طور پر انقلابِ فرانس تک پہنچتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے لیے آزادی افکار کا واحد راستہ مذہب اور بادشاہت دونوں سے آزادی کی صورت میں نکلتا تھا۔ آج بھی وہ لوگ مذہب کو اپنی اس آزادی پر ایک حملہ تصور کرتے ہیں جسے پانے کے لیے انہیں قرن ہا قرن ظلم کی بھٹی سے گزرنا پڑا۔ اس اصول اور مطالعے کا اطلاق اپنے معاشرے پر کرنا صائب نہیں۔ اگر کسی کے آباء اجداد گمراہ ہوں تو راہِ حق پانے کے لیے انہیں اپنے آباء سے بغاوت کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے آباء راہِ حق پر ہوں تو انہیں
اپنی موجودہ گمراہی چھوڑ کر اپنے آباء کے دین پر واپس آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔
دینِ اسلام دعوت دیتا ہے تفکر اور تدبر کی، یہاں بار بار دعوت دی جاتی ہے زمین و آسمان پر غور و فکر کرنے کی۔’’سانچ کو آنچ نہیں‘‘ کے مصداق اس دین کو غور و فکر سے کوئی نقصان نہیں۔ شہرِ علمؐ نے اپنی علمی میراث جس درِ علمؓ کو سونپی، وہاں سے صلائے عام ہے ’’سلونی سلونی‘‘ ’’— مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو!!‘‘ سچ سوال سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ سوال اور تحقیق سے صرف جھوٹ کی جان جاتی ہے۔
ہر ذی شعور اس حقیقت سے واقف ہے کہ ایک جہت قانون کی ہوتی ہے اور دوسری روحِ قانون کی۔ روحِ قانون سے غافل لوگ قانون کے نام پر قانون کی روح کو پامال کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین قانون بھی اگر کسی نا تراشیدہ قوم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے انصاف کے بجائے استحصال کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا رہا۔ جمہوریت سے لے کر مذہب تک ہم نے ہر نظام کو استحصال کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دنیا میں باقی مقامات پر جمہوریت آزادی اور حقوق کا تحفظ فراہم کرتی ہے اور ملوکیت و موروثیت کا سدِ باب ہے تو یہاں جمہوریت ذریعہِ استحصال کیوں ہے؟ کیا اس استحصال کی وجہ ہم جمہوریت کو قرار دیں گے؟ اسی طرح بہت سے مقامات پر ہم اپنی روایات کو دین پر ترجیح دے دیتے ہیں، بلکہ دین کے نام پر اپنے رسوم و رواج کا تحفظ چاہتے ہیں، جبکہ دین کی اصل تو حریت ہے— حریتِ فکر!
دینی تعلیمات میں واضح درج ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے، لڑکی اگر کہہ دے کہ میں خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خاندان اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، بغیر وجہ بتائے لڑکی کو علیحدگی کا حق حاصل ہے، لڑکی شوہر سے اپنے لیے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس پر سسرال کی خدمت فرض نہیں، وہ اپنے شوہر سے بچوں کو دودھ پلانے کی مد میں معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے، ذات پات نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، جہیز نکاح کا لازمہ نہیں ہے، شادی کا کھانا صرف ولیمہ ہے جو صرف لڑکے والوں کے ذمے ہے۔ بارات، مہندی، مایوں ڈھول تماشے سب غیر اسلامی طور طریق ہیں— یہاں دین ان تمام جاہلانہ رسوم کے راستے میں رکاوٹ ہے، جبکہ ہم ہیں کہ خود سے تصور کیے بیٹھے ہیں کہ شاید دین ان رسوم کو تحفظ دے رہا ہے۔ یہاں قصور ہماری فہم کا ہے، دین کا نہیں۔ دین تو آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ دینِ اسلام حریتِ فکر دیتا ہے۔ یہ دین ایک عام آدمی کو جرأت دیتا ہے کہ وہ حاکمِ وقت سے سرِ محفل پوچھ سکے کہ تمہاری قمیص مالِ غنیمت کی ایک چادر سے کیسے سل گئی؟ ’’وامرھم شوریٰ بینھم‘‘ کا کلیہ جمہوریت کے نصاب کی ایک بنیادی قدر ہے، اِس کا تعارف اسلام نے دیا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم جلد حاصل ہونے والی دنیا کی چکاچوند کے زیرِ اثر دینی اقدار سے منہ موڑ کر جلد ہی ملوکیت کی طرف راغب ہو گئے اور دین کو فقط مجموعہِ رسوماتِ عبودیت کے طور پر قبول کر لیا۔ ہم نوافل کی دوڑ میں معاشرتی فرائض بھول گئے۔ ہم مسجد کو فقط عبادت گاہ کے طور پر لیتے ہیں، اسے مقامی ویلفیئر سینٹر اور تعلیمی ادارے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔
کبھی غور کریں کہ جمود زدہ ذہن ملوکیت اور مُلّائیت کے دلدادہ کیوں ہیں اور یہ تصوف کے مخالف سمت ہی میں کیوں کھڑے نظر آتے ہیں۔ دراصل تصوف میں ان کا ذوقِ غلامی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں حُرّیتِ فکر سکھلائی جاتی ہے، روایت پرستی dogmatic belief کی جگہ روحانی تجربے پر زور دیا جاتا ہے، رسوم و رواج سے اعراض کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اندھی تقلید سے حذر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسے مذہبی تجربہ religious experience کہا ہے۔ مذہبی اور مسلکی تعصبات سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو دین کی روح ہمیں کربلا میں مشہود ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ کربلا میں حُریتِ فکر کا ایک عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے، یہاں معاشرے میں رائج ہوتی ہوئی ملوکیت کے خلاف عَلَم بلند کیا گیا، روحِ دین کو محفوظ کیا گیا، استحصال کرنے والے طبقے کے ہاتھوں دینی اقدار کو یرغمال بننے سے بچایا گیا۔
اہلِ فلسفہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، مذہب فلسفے کی ماں ہے۔ فلسفہ کھوج لگاتا ہے، یہ اپنا پرایا نہیں دیکھتا، یہ رسم و رواج بھی نہیں دیکھتا۔ ’سٹیٹس کو‘ کے محافظوں کو اصل خطرہ سوچنے والے دماغوں اور محسوس کرنے والے دلوں سے ہوتا ہے۔ فلسفہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے اور تصوف اس سے رابطے کا نام۔ مذہب— فلسفے اور تصوف کے درمیان ایک پل ہے، اور یہ پل صراط کی طرح بہت باریک ہے، اگر اسے بلڈوز نہ کر دیا جائے تو طالبینِ حقیقت، حقیقت سے عملی رابطے تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ ’سٹیٹس کو‘ کو اصل خطرہ اسلام سے ہے، سیکولرازم سے نہیں۔ ’سٹیٹس کو‘ توڑنے کا دوسرا راستہ سیاست ہے، یہ راستہ شارٹ کٹ تو ضرور ہے لیکن یہاں زور اور زر شامل ہے، اس لیے سچائی کے متلاشیوں کے لیے یہ راستہ قابلِ اعتبار نہیں رہتا۔
انقلاب کی اصل، فکر میں انقلاب لانا ہے۔ دنیائے انسانیت میں حقیقی انقلاب چودہ سو برس پہلے برپا ہوا تھا۔ یہ ایسا ہمہ گیر انقلاب تھا کہ انسان کی صدیوں سے جمود زدہ فکر جاگ اٹھی۔ اس انقلاب نے تمام اقدار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ہر قسم کے مذہبی، سیاسی ، معاشی اور معاشرتی ’سٹیٹس کو‘ کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس عالم گیر انقلاب کی صداؤں نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دور جب عبادت گاہوں کی تقدیس پر انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا، یہاں بتایا گیا کہ انسانی جان مال اور عزت کے تقدس کے سامنے مقدس ترین عبادت گاہ حرمِ کعبہ بھی کم ہے۔ جب غلام اور آقا الگ الگ جنس تصور ہوا کرتے تھے، اس نے غلام اور آقا کو ایک دستر خوان پر بٹھا دیا۔ جہاں لسانی اور نسلی تعصب کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، وہاں بتا دیا گیا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کا کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ سود کی حرمت دراصل انسانوں کی دنیا میں مالی استحصال کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی تدبیر تھی۔ دین ظلم اور ناانصافی کو مٹانے کا نصاب ہے۔ اس میں تحریف کرنے والے سب سے بڑے جرم اور ظلم کے مرتکب ہوئے۔ یہ دین ’سٹیٹس کو‘ یعنی معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ’سٹیٹس کو‘ کی حامی قوتیں اس دینِ فطرت سے فرار کی راہیں اختیار کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ آفاقی نصاب جو انسانی معاشرے میں رائج معاشی و معاشرتی ناہمواریاں ختم کرنے کا بانی و علم بردار ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اس میں دین کا کچھ دوش نہیں۔ دوش برگردنِ مقامی راوی ہے۔
دین اور ’سٹیٹس کو‘